حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
ولادت : ۱۰؍ ق ھ۔ وفات۷۳ھ
اسم گرامی: عبداللہ بن عمر
کنیت: ابو عبدالرحمن
سلسلۂ نسب :
والد کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے: عبد اللہ بن عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ قرط بن زراح بن عدی بن کعب قرشی العدوی بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔
والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے: زینب بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمع بن عمرو بن خصیص بن کعب بن لوی بن غالب بن ف?ر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔
ولادت: آپ کی ولادت ۱۰؍ق ھ مطابق۶۱۳ء کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔
اسلام :
ابھی آپ کم سن تھے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی دعاکی برکت سے حضرت عمر فاروق اسلام کی دولت لازوال سے مالا مال ہوئے اور کا شانہ فاروقی قال اللہ وقال الرسول کے نغمہ جاں فضا سے گونج اٹھا جس کے فیض سے ابن عمر بھی بہرہ ور ہوئے۔ خود بیان فرماتے ہیں: "لما اسلم عمر بن خطاب قال : أی اہل مکۃ انقل للحدیث؟ قالوا: جمیل بن معمر الجمحی فخرج عمر وخرجت ورائہ ، وانا غلیم اعقل کل ما رأیت، حتی اتاہ ، فقال: یاجمیل اشعرت انی قد اسلمت؟ فواللہ ما راجعہ الکلام حتیٰ قام یجر رداء ہ ، وخرج عمر یتبعہ، وانا معہ، حتی اذا قام علی باب المسجد صرخ: یا معشر قریش ان عمر قد صبأ. قال: کذبت ولکنی اسلمت ‘‘ (اسد الغابہ ج ۳، ص: ۳۳۸،۳۳۷، دارالکتب العلمیہ، بیروت)
یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو آپ نے ایک ایسے شخص کو تلاش کروایا جو اہل مکہ کو آپ کی حالت سے باخبر کرے۔ تو لوگوں نے جمیل بن معمر جمحی کے بارے میں بتایا۔ چناں چہ حضرت عمر اس کے پاس گئے ، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ اس وقت میں سمجھ دار بچہ تھا ہم وہاں پہنچے تو میرے والد نے اس سے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میںبتایا۔ بخدا! ابھی حضرت عمر کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ جمیل بن معمر چادر سمیٹتے ہوئے اٹھا، میں اپنے والد کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لیا، وہ مسجد حرام کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر بلند آواز سے یہ اعلان کرنے لگا، اسے گردوہ قریش !سنتے ہو عمر نے مذہب تبدیل کر لی ہے، تو حضرت عمر نے اس سے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، ارے !میں نے تومذہب اسلام قبول کیا ہے۔
ہجرت :
کفارومشرکین جب مسلمانوں کو ایذ او تکلیف پہنچانے لگے اوران کے درمیان مسلمانوں کا زندگی بسر کرنا کافی دشوار ہو گیا تو اللہ ورسول کی طرف سے ہجرت کا اذن عام ہوا، جہاں دیگر صحابہ نے ہجرت کی وہیں حضرت عمر بھی قال اللہ وقال الرسول پر عمل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ چناں چہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اپنے والد ماجد کی معیت میں مدینہ منورہ پہنچے اور یہیں آپ نے ہوش سنبھالا۔
غزوات میں حاضری :
آپ غزوہ بدر و احد میں دشمنان اسلام سے قتال کرنےاورجہاد فی سبیل اللہ کے ارادے سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے لیکن سرکار دو عالم ﷺ نے صغر سنی کی وجہ سے شرکت کرنے سے منع فرمایا۔
پھرغزوہ احزاب کے موقع پر جنگ میں شرکت کے ارادہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سر کار دو عالمﷺنے اجازت مرحمت فرمائی، اس اعتبار سے غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، آپ کی پہلی جنگ تھی۔ پھراس کے بعد بیعت رضوان، غزوہ خیبر، فتح مکہ فتح حنین، طائف، تبوک، فتح مصراور افریقہ کے معرکوں میں اعلائے کلمہ حق کے لیے کفار و مشرکین سے بر سر پیکار رہے اور شجاعت و بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ عہد فاروقی کے بعض فتوحات میں بھی آپایک پر جوش مجاہد اسلام کی حیثیت سے نمایاں نظر آتے ہیں۔
لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے اخیر اور عہد مرتضوی کے شروع میں جب عالم اسلام فتنہ و فساد اور آپسی خانہ جنگی سے دو چار ہوا تو آپ ملکی معاملات سے کنارہ کش ہو گئے اور عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بعض لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنانا چاہا اور آپ سے بیعت کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ آپ امیربن امیر ہیں ، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ نے فرمایا: جہاں تک میرا معاملہ ہے میں اپنے لیے ایک قطرہ خون بھی نہ بہنے دوں گا۔ لوگوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ اس بار گراں کو نہیں سنبھالیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے لیکن آپ نے اس دھمکی کی مطلقا پرواہ نہ کی اور خلافت جیسے بلند اعزاز کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔
عہدہ قضا سے انکار:
نفقہ واجتہاد ، علم و تقویٰ میں اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ نے کبھی کوئی منصب قبول نہیں فرمایا اور نہ ہی ملکی وسیاسی معاملات میں کسی خاص دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے قبل اکابر صحابہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے آنے لگا، چناں چہ لوگ آپ کی مجلس میں پیچیدہ ولایحل مسائل لے کرحاضرہونے لگے،اس طرح آپ کا شمار حضرت ابوہریرہ، ابوسعید خدری ، جابر بن عبد اللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے صاحب فتویٰ صحابہ میں ہونے لگا۔ حضرت مجاہد کا قول ہے :تر ک الناس ان یقتدوا بابن عمروھو شاب فلما کبراقتدوا بہ ۔ یعنی لوگوں نے جوانی میں ابن عمر کی اقتداو پیروی نہ کی لیکن جب آپ عمر دراز ( بوڑھے ) ہوئے تو لوگ آپ کی پیروی کرنے لگے اور احکام و مسائل دریافت کرنے لگے۔ ( الطبقات الکبری لابن سعد، ج ۴، ص۱۱۰، دوسری ایڈیشن، دارالکتب العلمیہ، بیروت)۱
جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابن عمر متقی و پرہیز گار و متبع سنت ہونے کے ساتھ مرجع خلائق بھی ہیں تو عہدہ قضا کی پیش کش کرتے ہوئے فرمایا: اقض بین الناس ، فقال لا اقضی بین الناس ولا أؤم اثنین ، قال فقال عثمان:أتقضینی؟ قال: لا ولکنہ بلغنی ان القضاۃ ثلاثۃ : رجل قضی بجہل فھو فی النار، رجل خاف ومال بہ الھواء فھو فی النار، ورجل اجتھد فأصاب فھو کفاف لا اجر لہ ولا وزر علیہ ، فقال : فان اباک کا یقضی ، فقال :ان ابی کان یقضی فاذا اشکل علیہ شیٔ سأل النبی ﷺواذا اشکل علی البنی ﷺ سال جبرائیل وانی لا اجد من اسال ، اما سمعت النی ﷺ یقول من عاذ باللہ فقد غاذ بمعاذ؟فقال عثمان: فانی اعوذ باللہ ان تستعملنی، فاعفاہ وقال: لا تخبربھذا احدا۔(مرجع سابق، ص :۱۰۹)
یعنی تم لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کرو، حضرت ابن عمر رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدہ قضا تسلیم نہ کرتے ہوئے کہا کہ امیرالمومنین امیں نہ تو دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اور نہ ہی کسی کی امامت کروں گا، حضرت عثمان نے کہا کہ کیا تم مجھے قاضی بناتے ہو؟ انھوں نے کہا نہیں، مجھے یہ معلوم ہوا کہ قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ، ایک وہ جو بغیر علم کے فیصلہ کرے تو وہ دوزخی ہے دو سر اوہ جو ظالم و جابر ہونے کے ساتھ ، فیصلہ کرنے میں خواہش نفس کی پیروی کرتا ہو تو وہ بھی جہنمی ہے، تیسر اوہ قاضی جو اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور وہ اس میں صواب پر بھی ہو تو وہ برابر ہے کہ اس کے لیے نہ اجر و ثواب ہے نہ گناہ ، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالٰی عنہ بھی تو قاضی تھے ؟ آپ نے جواب دیا کہ یقینا میرے والد قاضی تھے لیکن جب انہیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو نبی کریم ﷺسے دریافت کر لیتے تھے اور جب حضور اکرمﷺ کو دشواری ہوتی تھی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھتے تھے ، لیکن میری نگاہ میں کوئی ایسا شخص نہیں جس سے میں پوچھ لوں۔ کیا آپ نے سرکار مدینہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جس نے اللہ عزوجل سے پناہ مانگی اس نے جائے پناہ سے پناہ مانگی تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے عامل (گورنر) بنائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ کسی کو اس تعلق سے نہ بتانا۔
خدمت حدیث:
آپ ابتداے عمر ہی سے رسول اکرم ﷺکی پاکیزہ وبابرکت صحبت سے مستفیض ہونے والے خوش نصیب صحابہ میں سے تھے۔ سن رشد کو پہنچتے ہی تحصیل علم قرآن کے ساتھ حدیث نبوی کی طلب و جستجو میں لگ گئے چناں چہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو رسول اکرم ﷺکے اقوال وارشادات کو بغور سماعت کرتے اور اسے یاد کر لیتے بسا اوقات بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو دیگر صحابہ سے دریافت کر کے محفوظ کر لیتے تھے۔ آقائے کریم کی فیض صحبت اور خود آپ کے اندر شوق علم نے آپ کو علم حدیث کا بحر بیکراں بنا دیا تھا جس سے لاکھوںتشنگان علوم نبوت سیراب ہوئے اور آپ کی مستند و معتبر ذات سے حدیث نبوی کی کافی اشاعت ہوئی۔
روایت حدیث میں احتیاط :
آپ کمال حفظ و ضبط کے باوجود احادیث نبوی کی روایت میں حد درجہ محتاط تھے۔ ’’ عن ابی جعفر محمد بن علی قال:لم یکن من اصحاب رسول ﷺ احداحذر اذا سمع من رسول ﷺ شیئا الا یزید فیہ ولا ینقص منہ عنداللہ بن عمر- ( مرجع سابق، ص ۷۰۱)
ابو جعفر محمد بن علی کا بیان ہے : ’’صحابہ کی جماعت میں روایت حدیث میں ابن عمر سے زیادہ محتاط کسی کو نہ دیکھا۔ وہ حدیث میں اضافہ و نقصان سے ڈرتے تھے۔
حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں : صحبت ابن عمرفماسمعتہ یحدث عن النبی ﷺ حدیثا واحدا۔
یعنی میں مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا تو میں نے اس درمیان انہیں نبی کریم ﷺ سے ایک بھی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔
حضرت امام شعبی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: جالست ابن عمر سنۃ فما سمعتہ یحدث عن رسول اللہ ﷺ شیئا. یعنی میں حضرت ابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک سال تک حاضر ہوا تو اس مدت میں انھیں نبی کریم ﷺسے کوئی حدیث روایت کرتے ہوئے نہیں سنا۔
اس حزم واحتیاط کے باوجود آپ کا شمار مکثرین صحابہ میں ہوتا ہے ، آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۱۶۳۰( ایک ہزارچھ سوتیس) ہے۔ ۱۷۰؍ احادیث متفق علیہ ہیں یعنی امام بخاری ومسلم نے ان احادیث کو صحیحین میں بیان کیا ہے ،۸۱ / احادیث کوصرف امام بخاری نے اور۳۱/ احادیث امام مسلم نے تنہا روایت کیا ہے۔ اور بقیہ احادیث دیگر کتب صحاح مسانید و سنن میںموجود ہیں۔ (السنہ قبل التددین، ص:۴۷۱، دارالفکر)
روایت حدیث:
رسول اکرمﷺنے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ، حضرت علی بن طالب، حضرت ابوذر غفاری، حضرت معاذ بن جبل، ام المومنین حضرت عائشہ ، ام المومنین حضرت حفصہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال، حضرت زید بن ثابت اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حدیث کی روایت کی ہے۔
تلامذہ :
آپ کے چشمہ فیض سے دنیائے اسلام کے تشنگان علوم نصف صدی تک سیراب ہوتے رہے۔ چناں چہ آپ سے ایک کثیر جماعت نے روایت کیا۔ ان میں سے نامور و مقتدر ہستیوں کے نام یہ ہیں: ان کی اولاد میں سالم، عبداللہ، حمزہ، زید، عبید اللہ و عمر آپ کے آزاد کردہ غلام نافع ، حفص بن عاصم بن عمر، خالد بن اسلم، موسیٰ بن طلحہ اور کبار تابعین میں سے سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص، ابو عبدالرحمن التصدی مسروق، مصعب بن سعد، ابو بردہ بن ابی ،موسیٰ عبد اللہ بن دینار، زید، خالد، عروہ بن زبیر ، بشر بن سعید، عطا، مجاہد، محمد بن سیرین، سعید بن جبیر، ثابت بنانی، عکرمہ و غیرہم (تہذیب التہذیب، ج۵، ص:۳۳۹، دار صادر، بیروت)
بحیثیت فقیہ:
حدیث کے بعد فقہ کا درجہ ہے۔ آپ فقہ واجتہاد کے بھی امام تھے ، لوگ بکثرت دینی مسائل آپ سے دریافت کیا کرتے تھے ، آپ کی ساری عمر علم وافتا میں بسر ہوئی، آپ کے نفقہ واجتہاد کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ فقہ مالکی کی اساس و بنیاد آپ ہی کے فتاویٰ پر ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں:
’’اقام ابن عمر بعد وفاۃ رسول اللہ ﷺ ستین سنۃ تقدم علیہ وفود الناس‘‘ (الحدیث والمحدثون، ص ۱۴۱)
یعنی رسول اکرم ﷺکی حیات ظاہری کے بعد ابن عمر ساٹھ برس تک باحیات رہے ، آپ کی بارگاہ میں لوگوں کے وفود آتے رہے۔ فقیہ امت ہونے کے باوجود آپ اپنے فتاوی میں بڑے محتاط تھے اگر آپ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جس کے بارے میں آپ کو قطعی علم نہ ہوتا تو صاف طور پر لاعلمی کا اظہار فرمادیتے تھے۔ ’’سئل ابن عمر عن شیٔ فقال لا علم بہ، فلما ادبر الرجل قال لنفسہ سئل ابن عمر عما لا علم لہ بہ فقال لا علم لہ بہ. (الطبقات الکبری، لابن سعد، ج ۴، ص: ۱۱۷)
حضرت امام مالک کا بیان ہے کہ ابن عمر ائمہ دین میں سے تھے ، ان کے فتاوی جمع کیے جائیں تو ایک ضخیم کتاب جمع ہو جائے گی۔
امام مالک ہی کا بیان ہے ، فرماتے ہیں مجھ سے میرے شیخ ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ کسی کی رائے کو عبد اللہ بن عمر کی رائے کے برابر و ہم پلہ نہ سمجھو، وہ حضور اکرم ﷺکے بعد ساٹھ سال تک باحیات رہے ، ان سے حضور اکرمﷺاور آپ کے صحابہ کی کوئی بات مخفی نہیں تھی۔
اسی طرح ایک شخص مسئلہ دریافت کرنے آیا تو آپ نے لاعلمی کا اظہار کیا پھر اہل مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا: ’’اتریدون ان تجعلوا ظھورنا جسورا فی جھنم؟ تقولون افتانا ابن عمر۔‘‘ (الاصابۃ، ج ۴، ص : ۱۲۰، دارالکتب العلمیہ )
یعنی تم لوگ مجھے جہنم کا پل بنانا چاہتے ہو؟ تاکہ تمہیں یہ کہنے کا موقعہ ملے کہ ابن عمر نے ایسا فتویٰ دیا ہے۔
عبد اللہ بن عمر اور مسئلہ رفع یدین: امام مجاہد جو آپ کے شاگرد ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے اور رکوع میں جانے سے قبل اور اٹھنے کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ شرح معانی الآثار میں ہے:
"عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولیٰ من الصلاۃ۔‘‘(شرح معانی الآثار، ج:۱، ص:۱۶۳)
یعنی امام مجاہد سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر کی اقتدا میں نماز پڑھی تو انھیں صرف تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔
اپنے اس عمل کے باوجود آپ رکوع کے وقت رفع یدین والی حدیث کی روایت کرتے تھے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس بات کے قائل تھے کہ نبی کریمﷺکے فعل سے لوگوں کو باخبر کیا جائے خواہ سر کار کا فعل ابتدائے اسلام کا ہویا سرکار دو عالم بیا کے حیات ظاہری کے آخری ایام کا ہو۔
ابن عمر اور مسئلہ سنت فجر:
آپ فجرکی جماعت کھڑی ہونے کے وقت سنت فجر کے جواز کے قائل تھے چناں چہ آپ کے آزاد کردہ غلام و شاگرد حضرت نافع فرماتے ہیں: " ایقظت ابن عمر لصلوٰ ۃ الفجر وقد اقیمت الصلوٰۃ فقام وصلیٰ رکعتین‘‘. (مرجع سابق ، ۴۸۶، دارالکتب العلمیہ )
یعنی میں نے ابن عمر کو نماز فجر کے لیے جگایا جب کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو آپ اٹھے اور دور کعت سنت فجر پڑھی۔
ابن عمر اور مسئلہ قراء ت خلف الامام: آپ نے قراء ت خلف الامام کے تعلق سے فرمایا: "من صلی وراء الامام کفاہ قراء ۃ الامام ‘‘ (سنن الکبری للبیھقی ،ج ۲ ص ۱۶۱)
یعنی جو امام کی اقتدا میں نماز پڑھے تو امام کی قراء ت اس کے لیے کافی ہے۔
آپ کے شاگرد امام نافع کہتے ہیں کہ جب آپ سے سوال ہوا "ھل یقرأ احد خلف الامام‘‘ کیا امام کے پیچھے قراء ت کرنے کی اجازت ہے ؟ تو آپ نے فرمایا: اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراء ۃ الامام واذا صلی وحدہ فلیقرأ. (شرح معانی الآثار ، ج:۱، ص: ۲۸۴،دارالکتب العلمیہ)
تم میں سے کوئی جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراء ت اس کے لیے کافی ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو قراء ت کرے۔آثار نبوی کی اتباع : آپ نے خالص اسلامی ماحول میں تربیت پائی۔ ابتدا ہی سے بارگاہ رسالت میں مسلسل حاضری صرف اپنی زندگی کو اسوہ رسول کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے دیتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں حاضری اور علم واخلاق کے اکتساب نے آپ کو خلق پیغمبر کا نمونہ بنادیا تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ کی پوری زندگی بلکہ آپ کی ہر ہرادا سیرت پاک کا نمونہ اورسنت نبوی کا آئینہ دار تھی، آپ کی ذات حدیث رسول اور سنت نبوی کی عملی تعبیراورچلتی پھرتی تصویر تھی۔
سیرت رسول کی مثالی اتباع نے ابن عمر کے زہد و ورع کو اس درجہ بلند کر دیا تھا کہ اپنے معاصرین میں وہ ممتازاور منفرد نظر آتے۔
سرکار دوعالم ﷺنے ایک دفعہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ان اخاک رجل صالح لو کان یقوم من اللیل۔یعنی اے حفصہ ! تیرا بھائی ابن عمر صالح اور نیک انسان ہے اگر وہ شب بیداری کرتے تو بہت اچھاہوتا ( یعنی نماز تہجد پڑھتے )
حضور کے اس ارشاد کو سننے کے بعد حضرت ابن عمر نے کبھی نماز تہجد ترک نہیں فرمایاخود فرماتے ہیں: ’’ماترکت قیام اللیل بعد ذالک‘‘
سفر و حضر میں بھی قدم قدم پر رسول کریم ﷺ کی اتباع فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ سواری سےاسی جگہ اترتے جہاں سرکار مدینہ اترا کرتے تھے اور اسی مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے جہاں حضور اکرم ﷺ پڑھا کرتے تھے بلکہ اگر سرکار نے راستہ میں کسی درخت کو پانی دیا ہوتا تو ابن عمر بھی رسول کریمﷺکی اتباع میں پانی دیتے تھے۔
آثار نبوی کی پیروی کی برکت تھی کہ آپ مناسک حج کے سب سے زیادہ جانکار تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں :ماکان احد یتبع آثار النبی ﷺ فی منازلہ کما کان یتبعہ ابن عمر‘‘. (طبقات ابن سعد، ج ۴، ص : ۳۹۰)
اکابر کے اقوال:
آپ نے علم و فضل ، زہد و ورع، پاکیزگی نفس، اتباع سنت ، تفقہ فی الدین اور عشق رسول کا پیکر بن کرزندگی کے شب و روز گزارے اور امت مسلمہ کے لیے چراغ ہدایت بنے رہے۔ امت مسلمہ کے اکابر نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا:
عبداللہ ا بن مسعود:’’ان املک شباب قریش لنفسہ عن الدنیا عبد اللہ بن عمر‘‘. (السنہ قبل التدوین، ص: ۴۷۰)
ابن عمر قریش کے جوانوں میں سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہیں۔
جابر بن عبد اللہ : "مامنا من احد ادرک الدنیا الا مالت بہ ومال بھا غیر عبد اللہ بن عمر. (تہذیب التہذیب ، ج ۵، ص : ۳۳۰) ابن عمر کے علاوہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جو دنیا کی طرف مائل نہ ہوا۔
ابو سلمہ بن عبد الرحمن: ’’کان عمر فی زمانہ لہ فیہ نظراء وکان ابن عمر فی زمان لیس لہ فیہ نظیر ‘‘( الاصابۃ فی تمیز الصحابہ، ج ۴، ص: ۱۵۸،دار الکتب العلمیہ)
عمر ایسے زمانے میں تھے کہ ان کی نظیر تھی اور ابن عمر ایسے زمانے میں تھے کہ ان کی نظیر نہیں تھی۔
محمد بن حنفیہ : کان ابن عمر حبر ھذہ الامۃ ‘‘(السنہ قبل التدوین ، ص ۴۶۹) ابن عمر امت مسلمہ کے بڑے عالم تھے۔
اوصاف:
آپ متعد د صفات و کمالات کے حامل تھے ، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نمونہ عمل ہے ، آپ کا ہر عمل ارشاد رسول و سنت رسول کے مطابق ہوا کرتا تھا، چناں چہ آپ بازار صرف اس لیے تشریف لے جاتے تھے تاکہ آپ لوگوں کو سلام کریں اور لوگ آپ کو سلام کریں اور اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ ایسے ہی آپ کا معمول تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تو روضہ کرسول پرحاضر ہوتے اور حضور اکرم ﷺکی بارگاہ میں اور حضرت ابو بکروعمررضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں سلام کرتے تھے۔
وفات:
آپ کی وفات کے سلسلہ میں بھی قدرے اختلاف ہے ، ایک قول یہ ہے کہ آپ کی وفات ۷۴ ھ میں مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر ۸۴/ سال تھی، یہ آپ کے صاحبزادے سالم کی روایت ہے جب کہ فضل بن دکین نے بیان کیا کہ آپ کی وفات ۷۳ھ میں ہوئی۔
آپ کی وفات کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف خطبہ دے رہا تھا، اور اسے طول کر تا جار ہا تھا کہ نماز عصر نکل جانے کا اندیشہ تھا، اتفاق سے حضرت ابن عمر وہاں تشریف فرما تھے آپ اٹھے اور حجاج کا بے محل خطبہ نا پسند کرتے ہوئے فرمایا:’’ان لشمس لا تنتظرک ‘‘آفتاب تیرا انتظار نہیں کرے گا، حجاج بن یوسف نے آپ سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا اورایک شخص کو انتقام لینے کے لیے مامور کر دیا، جس نے ایام حج میں عرفات سے واپسی پر لوگوں کی بھیٹر میں زہر آلود نیزے کی نوک آپ کے پاؤں میں چھودی، یہ زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کے اثر کی وجہ سے آپ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے ، اور یہی زخم آپ کی وفات کا باعث ہوا۔
آپ کی ولی آرزو، تمنا اور خواہش یہ تھی کہ آپ کی وفات مدینتہ الرسول میں ہو، چناں چہ جب آپ کی حالت نازک ہوگئی تو آپ نے اپنے صاحبزادے سالم کو وصیت کی کہ اگر مکہ مکرمہ میں میری موت ہو جائے تو مجھے حدود حرم کے باہر دفن کرنا اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس سرزمین میں مدفون ہوں جہاں سے میں نے ہجرت کی ہے ، وصیت کے کچھ دنوں بعد آپ کی وفات ہو گئی۔
وصیت کے مطابق لوگوں نے حرم کے باہر دفن کرنا چاہا مگر جان کی وجہ سے آپ کی یہ وصیت پوری نہ ہو سکی اور آپ کو مجبو را مقبرہ مہاجرین میں جو ذی طوی کے قریب مقام فی میں واقع ہے سپردخاک کیا گیا آپ کی نماز جنازہ حجاج بن یوسف نے پڑھائی۔



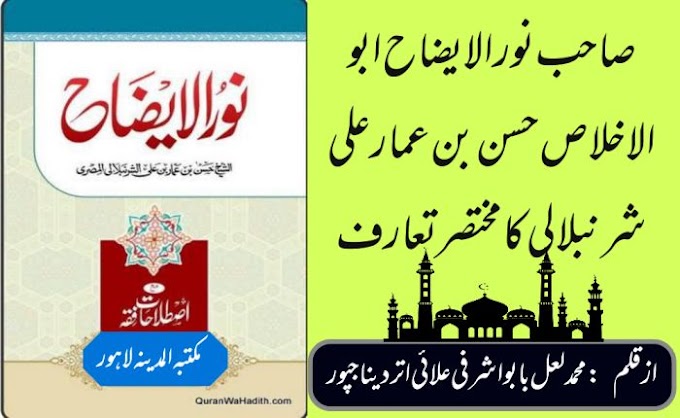








0 Comments